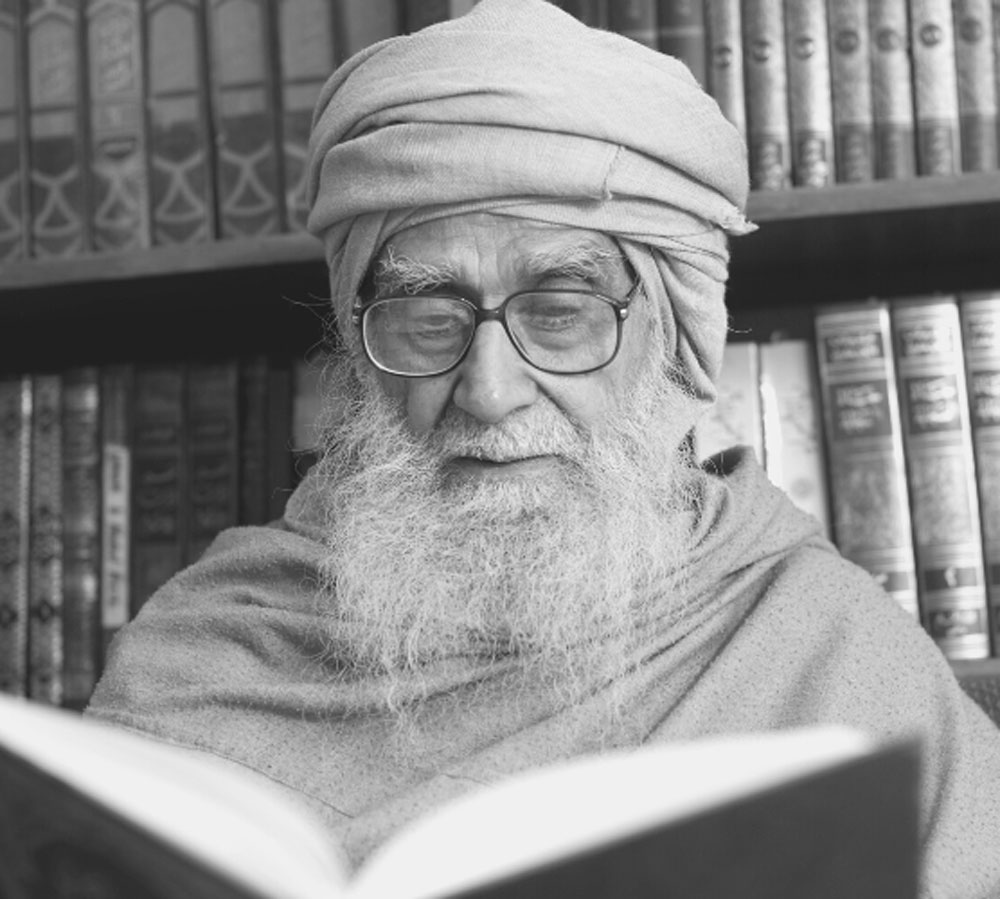کچھ نئی حقیقتیں
علامہ شبلی نعمانی اپنی کتاب ’’الغزالی‘‘ کے دوسرے حصہ میں ’’معاد یا حالات بعد الموت‘‘کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں … ’’مذہب کی روح رواں جو کچھ کہو، معاد(آخرت) کا اعتقاد ہے۔ مذہب میں جو کچھ تاثیر ہے اور افعال انسانی پر مذہب کا جو اثر پڑتا ہے، وہ اسی اعتقاد کی بدولت ہے۔ لیکن جس قدر وہ مہتم بالشان ہے اسی قدر عسیر التصور (unthinkable) ہے۔ ایک بدوی شاعر الحاد کے لہجہ میں کہتا ہے:
حَيَاةٌ ثُمَّ مَوْتٌ ثُمَّ بَعْثٌ زندگی، پھرموت، پھردوبارہ جی اٹھنا!
حديثُ خرافةٍ يا أمَّ عمرو میری بیگم! یہ تو خرافات کی باتیں ہیں
اس مرحلہ میں جو مشکلیں ہیں ان میں پہلا اور سب سے مشکل بقائے روح کا مسئلہ ہے۔ یعنی یہ ثابت کرنا کہ روح جسم سے جدا کوئی چیز ہے۔ مادیین کا خیال ہے کہ روح کوئی جداگانہ چیز نہیں، بلکہ جس طرح دوائوں کو ترکیب دینے سے ایک مزاج خاص پیدا ہو جاتا ہے، یا تاروں کی خاص ترکیب سے خاص خاص راگ پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح عناصر کے خاص طور پر ترکیب پانے سے ایک مزاج خاص پیدا ہو جاتا ہے جو ادراک اور تصور کا سبب ہوتا ہے اور اسی کا نام روح ہے۔
روح کے ثابت کرنے کے بعد دوسرا مرحلہ اس کی بقا کا ثابت کرنا ہے، یعنی یہ کہ جسم کے فانی ہونے پر وہ باقی رہ سکتی ہے۔‘‘ (صفحہ 171-72)
اس کے بعد علامہ شبلی مضنون صغیر اور مضنون کبیر سے ان مباحث پر امام غزالی کے خیالات نقل کرتے ہوئےلکھتے ہیں:
’’امام صاحب نے روح کی جو حقیقت بیان کی اور اس پر جو دلائل پیش کیے، یونانیوں سے ماخوذ ہیں۔ ارسطو نے اثو لو جیا میں بعینہ یہ تقریر کی ہے اور بوعلی سینا نے اس کو مختلف پیرایوں میں آب و رنگ دے کر ادا کیا ہے، لیکن یہ امر بظاہر تعجب انگیز ہے کہ جو سب سے مقدم امر تھا، یعنی روح کا اثبات، امام صاحب نے اسی کو چھوڑ دیا۔ روح کا جوہر ہونا، غیرجسمانی ہونا، یہ فرعی امور ہیں۔ پہلے یہ ثابت کرنا چاہیے کہ روح کوئی شئے بھی ہے یا نہیں۔‘‘ (ص 174)
اس کے بعد اپنی طرف سے لکھتے ہیں… ’’اصل یہ ہے کہ روح کا وجود ایک وجدانی امر ہے، غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ادراک و تعقل محض مادہ کا کام نہیں۔ مادہ ایک بے حس، بے جان اور لایعقل چیز ہے۔ دقیق خیالات اور علوم و فنون مادہ سے انجام نہیں پا سکتے۔ بلکہ کوئی اور جوہر لطیف ہے جس سے یہ کرشمے سرزد ہوتے ہیں اور اسی کا نام روح ہے۔‘‘
اس کے بعد لکھتے ہیں:’’لیکن یہ استدلال وجدانی ہے۔ (بوعلی سینا نے روح کے اثبات پر اشارات میں لمبی چوڑی دلیل پیش کی ہے۔ لیکن وہ یونانیوں کے عام دلائل کی طرح صرف لفظوں کا کھیل ہے) اگر کوئی منکر انکار پر آمادہ ہو اور کہے کہ… ’’تم نے جو کچھ کہا عین دعویٰ کا اعادہ ہے، دلیل نہیں۔ ممکن ہے مادہ ہی ایک خاص ترکیب پا کر ان نیرنگیوں کا مظہر ہو۔ کلوں سے جو عجیب و غریب حرکتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ ارغنوں سے جو دلکش اور موثر نغمے پیدا ہوتے ہیں، ان میں روح کا کون سا شائبہ ہے۔‘‘ تو ہم دلیل سے اس کی زبان بند نہیں کرسکتے۔ یہی سبب تھا کہ امام صاحب نے روح کے ثبوت پر کوئی منطقی دلیل نہیں پیش کی۔‘‘ (صفحہ 175)
مولانا شبلی نعمانی مرحوم نے اس بحث کو یہیں ختم کر دیا ہے اور ایک عالم کی 1901ء کی تصنیف میں شاید اتنا ہی کہا جا سکتا تھا۔ مگر میں اس پر یہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ جدید تحقیقات نے واقعات و حقائق کے کچھ ایسے نئے گوشے کھولے ہیں، جس کے بعد ایک حد تک یہ کہا جا سکتا ہے کہ روح کا جسم سے الگ ایک مستقل وجود ہونا یا جسم کے فنا ہونے کے بعد روح کا باقی رہنا محض وجدانی چیز نہیں رہا، بلکہ ایک ایسی حقیقت بن چکا ہے جس کو تجرباتی دلیل سے ثابت کیا جا سکتا ہے۔
جسم کے بارے میں سائنس نے دریافت کیا ہے کہ وہ بے شمار چھوٹے چھوٹے خلیوں (cells) کا مرکب ہے جن کی تعداد ایک متوسط جسم میں ایک ہزار ارب کے قریب ہوتی ہے۔ یہ خلیے ہر آن ٹوٹ کر ختم ہوتے رہتے ہیں۔ غذا ہضم ہو کر ہمارے جسم کے لیے وہ خلیے مہیا کرتی ہے جو ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے ہر روز درکار ہوتے ہیں۔ گویا جسم نام ہے ایک ایسی عمارت کا جو کھربوں اینٹوں سے ملکر بنا ہو اور ہر آن اپنی اینٹوں کو بدلتا رہتا ہو۔ اب اگر روح جسم کا ایک مظہر ہے تو جس طرح مشین کا ایک پرزہ ٹوٹنے سے پوری مشین متاثر ہو جاتی ہے اور باجے کا ایک تار خراب ہو جانے سے اس کی آواز پر اثر پڑ جاتا ہے اسی طرح جسم کے مرکبات بدلنے یا ضائع ہونے سے روح میں بھی تبدیلیاں ہونی چاہئیں۔ مگر ایسا نہیں ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ روح جسم سے الگ ایک چیز ہے جو بذات خود اپنا وجود رکھتی ہے۔ چنانچہ ایک سائنس داں نے انسانی ہستی کو اس کے جسم کے مقابلے میں ایک ایسی مستقل بالذات چیز قرار دیا ہے جو مسلسل تغیرات کے اندر غیر متغیر حالت میں اپنا وجود باقی رکھتی ہے۔ اس کے الفاظ میں:
‘‘Personality is changelessness in change.’’
اس خیال کی مزید تصدیق نفسیات کے اس انکشاف سے ہوتی ہے جس کو تحت شعور یا لاشعور کہا جاتا ہے اور جو انسانی ذہن کا نسبتاً زیادہ بڑا حصہ ہے۔ لاشعور کے بارے میں اب یہ تقریباً مسلمہ طور پر مان لیا گیا ہے کہ جو خیالات اس کے اندر جگہ پاتے ہیں وہ تاحیات بالکل یکساں حالت میں باقی رہتے ہیں۔ فرائڈ اپنے اکتیسویں لیکچر میں کہتا ہے:
’’منطق کے قوانین بلکہ اضداد کے اصول بھی لاشعور کے عمل پر حاوی نہیں ہوتے۔ مخالف خواہشات ایک دوسرے کو زائل کیے بغیر اس میں پہلو بہ پہلو ہمیشہ موجود رہتی ہیں … لاشعور میں کوئی ایسی چیز نہیں جو نفی سے مشابہت رکھتی ہو اور ہمیں یہ دیکھ کر حیرت ہوئی ہے کہ لاشعور کی دنیا میں فلسفیوں کا یہ دعویٰ غلط ہو جاتا ہے کہ ہمارے تمام دماغی افعال وقت اور فاصلہ کے درمیان واقع ہوتے ہیں۔
لاشعور کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں جو وقت کے تصور سے مطابقت رکھتی ہو۔ لاشعور میں وقت کے گزرنے کا کوئی نشان نہیں اور یہ ایک حیرت انگیز حقیقت ہے جس کے معنی سمجھنے کی طرف ابھی تک فلسفیوں نے پوری توجہ نہیں کی کہ وقت کے گزرنے سے ذہنی عمل میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ ایسے خیالات (conative impulses) جو کبھی لاشعور سے باہر نہیں آئے، بلکہ وہ ذہنی تاثرات بھی جنہیں روک کر لاشعور میں دبا دیا گیا ہو، فی الواقع غیر فانی ہوتے ہیں اور دسیوں سال تک اس طرح سے محفوظ رہتے ہیں گویا ابھی کل وجود میں آئے ہیں۔‘‘
New Introductory Lectures on Psychoanalysis, London. 1949, p. 99
لاشعور کے عمل کا وقت کی گرفت سے آزاد ہونا، ظاہر کرتا ہے کہ لاشعور جسم سے الگ اپنا کوئی وجود رکھتا ہے۔ کیونکہ جسم کے بارے میں یہ مسلم ہے کہ وہ وقت اور فاصلہ کے قوانین کا پابند ہے اور انہیں حدود کے اندر اس کے تمام مظاہر واقع ہوتے ہیں۔ اب اگر روح جسم ہی کا ایک ظہور خاص ہوتی تو جسم کی طرح اس کو بھی لازماً وقت اور فاصلہ کے قوانین کا پابند ہونا چاہیے تھا اور جب کہ تجربہ یہ ثابت کرتا ہے کہ ایسا نہیں ہے تو اس کا لازمی مفہوم یہ ہے کہ روح اپنی نوعیت میں جسم سے مختلف ایک چیز ہے جو اس سے الگ اپنا مستقل وجود رکھتی ہے۔ جسم سے روح کا تعلق مشین اور حرکت یا باجے اور راگ کا نہیں ہے۔ کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو جس طرح حرکت اور راگ پر بعینہ وہی قوانین مترتب ہوتے ہیں جو مشین اور باجے پر مترتب ہوتے ہیں۔ اسی طرح روح پر بھی یقینا انہیں قوانین کا ترتب ہوتا جو جسم کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔
دوسری چیز جس کا میں یہاں حوالہ دینا چاہتا ہوں وہ سائیکیکل تحقیقات (psychical research) کے نتائج ہیں، جو خالص تجرباتی اور مشاہداتی سطح پر موت کے بعد زندگی کے وجود کو ثابت کرتے ہیں۔ اس میں ہمارے نقطہ نظر سے مزید دلچسپی کی بات ہے کہ یہ بقائے محض کو ثابت نہیں کرتے بلکہ عین اس شخصیت کی بقا کو ثابت کرتے ہیں جس سے ہم موت سے پہلے واقف تھے۔
انسان کی بہت سی ایسی خصوصیات ہیں جو بذات خود تو پہلے سے موجود تھیں، مگر ان پر سائنسی انداز سے غور و فکر نہیں ہوا تھا۔ مثلاً خواب دیکھنا انسان کی قدیم ترین خصوصیت ہے۔ مگر جدید دور میں خواب کے مطالعہ سے جو نفسیاتی حقائق معلوم کیے گئے ہیں، ان سے قدیم دور کے لوگ ناآشنا تھے۔ اسی طرح اور بہت سے مظاہر ہیں جن کے متعلق موجودہ زمانہ میں باقاعدہ اعداد و شمار جمع کیے گئے اور سائنسی انداز سے ان کا تجزیہ کیا گیا۔ اس طرح جدید مطالعہ کے ذریعہ ان واقعات سے نہایت اہم نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ اسی میں سے ایک سائیکیکل ریسرچ ہے جو جدید نفسیات کی ایک شاخ ہے اور جس کا مقصد انسان کی مافوق العادت صلاحیتوں کا تجزیاتی مطالعہ ہے۔ اس قسم کی تحقیقات کے لیے سب سے پہلا ادارہ 1882ء میں انگلینڈ میں قائم ہوا، اور 1889ء میں اس نے سترہ ہزار اشخاص سے رابطہ قائم کرکے وسیع پیمانے پر اپنی تحقیقات شروع کر دیں۔ یہ اب بھی مطالعہ نفسیات کا ادارہ (Society for Psychical Research) کے نام سے موجود ہے اور اسی نوعیت کے دوسرے ادارے دوسرے ملکوں میں کام کر رہے ہیں۔ ان اداروں نے مختلف مظاہروں اور تجزیات کے ذریعہ ثابت کیا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی شخصیت کسی پراسرار شکل میں باقی رہتی ہے۔
فلسفہ نفسیات کے بہت سے ماہرین جنہوں نے ان شواہد کا غیر جانبدارانہ مطالعہ کیا ہے وہ زندگی بعد موت کو بطور واقعہ تسلیم کرنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ براؤن یونیورسٹی میں فلسفہ کے پروفیسر سی،جے، ڈوکاس (C. J. Ducasse) نے اپنی کتاب کے سترہویں باب میں زندگی بعد موت کے تصور کا فلسفیانہ اور نفسیاتی جائزہ لیا ہے۔ پروفیسر موصوف اگرچہ مذہب کے معنوں میں اخروی زندگی کے تصور پر عقیدہ نہیں رکھتے، مگر ان کا خیال ہے کہ ایسے شواہد موجود ہیں کہ مذہب کے عقیدہ سے الگ کرکے زندگی کی بقاء کو ہمیں ماننا پڑتا ہے۔
اس باب کے آخری حصہ میں وہ سائیکی کل ریسرچ کی تحقیقات کا جائزہ لینے کے بعد لکھتے ہیں:
’’کچھ بہت ہی ذہین اور ذی علم افراد جنہوں نے سالہا سال تک نہایت تنقیدی نظر سے متعلقہ شہادتوں کا مطالعہ کیا ہے۔ وہ بالآخر اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ کم از کم کچھ شواہد ایسے ضرور ہیں جن میں صرف بقائے روح کا فرضیہ (survival hypothesis) ہی معقول اور ممکن نظر آتا ہے، ان کی کوئی دوسری توجیہہ نہیں کی جا سکتی۔
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ موت کے بعد زندگی کا عقیدہ جس کو بہت سے لوگ مذہبی طور پر مانتے ہیں نہ صرف یہ کہ صحیح ہو سکتا ہے بلکہ شاید وہ ایک ایسا عقیدہ ہے جس کو تجزیاتی دلیل (empirical proof) سے ثابت کیا جا سکتا ہے اور اگر ایسا ہے تو قطع نظر اس من گھڑت کے جو زندگی بعد موت کی نوعیت کے متعلق اہل مذاہب نے فرض کر لی ہے، قطعی معلومات بالآخر اس کے بارے میں حاصل ہو سکیں گی، مگر ایسی صورت میں اس کی مذہبی نوعیت کو ماننا ضروری نہیں ہوگا۔‘‘
A Philosophical Scrutiny of Religion, pp. 407-10
مصنف نے زندگی بعد موت کو بطور حقیقت تسلیم کرتے ہوئے اس کی مذہبی نوعیت کا انکار کیا ہے۔ یہ صرف تسکین نفس کی ایک کوشش ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ موت کے بعد بھی اگر زندگی باقی رہتی ہے تو اس کی کوئی بھی تعبیر مذہبی نوعیت کے سوا نہیں ہو سکتی۔