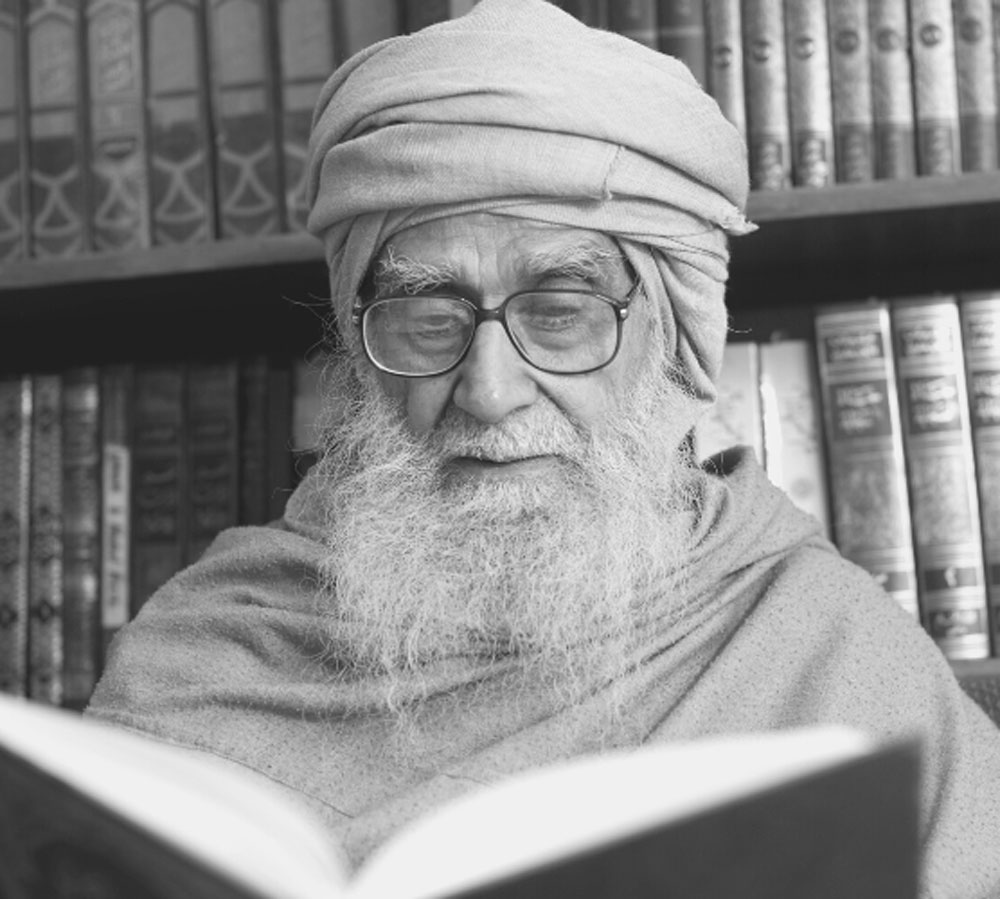اسلام کے نام پر غیر اسلام
(Islamization of non-Islam)
مذہب کی تاریخ کایہ ایک عام ظاہرہ ہے کہ بعد کے زمانے میں مذہب کی اصل تعلیم گُم ہوجاتی ہے اور خود ساختہ چیزوں کو مذہب کا درجہ دے دیا جاتا ہے۔ مثلاً مسیحیت (Christianity) دو ہزار سال پہلے حضرت مسیح کی تعلیمات پر مشتمل تھی۔ آج مسیحیت ایک ایسے مذہب کا نام ہے جس کو مسیحی چرچ نے بعد کے زمانے میں بطو خود وضع کیا۔
ٹھیک یہی معاملہ خود مسلمانوں کے ساتھ بھی بعد کے زمانے میں پیش آیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگی طورپر مسلمانوں کو اِس خطرہ سے متنبہ کردیا تھا۔ مثلاً حدیث میں آیا ہے کہ: لتتبعن سنن من کان قبلکم (البخاری، کتاب الاعتصام، باب قول النبی لتتبعن) یعنی تم لوگ ضرور پچھلے مذہبی گروہوں کی پیروی کروگے۔ اِسی طرح آپ نے فرمایا:بدأ الإسلام غریباً وسیعود کما بدأ ( صحیح مسلم، کتاب الإیمان، باب بیان أن الإسلام بدأ غریباً) یعنی اسلام شروع ہوا تو وہ اجنبی تھا، اور بعد کو وہ پھر اجنبی ہوجائے گا۔
اِس کا یہ مطلب نہیں کہ اسلام بعد کے زمانے میں معدوم ہوجائے گا۔ یہ قانونِ فطرت کے خلاف ہے۔ چناں چہ ایسا نہ کسی اور مذہب کے ساتھ ہوا، اور نہ اسلام کے ساتھ ایسا ہوسکتاہے۔ اِس حدیث کا مطلب صرف یہ ہے کہ اسلام کا اصل متن (text) اگر چہ محفوظ رہے گا، لیکن مسلمان عملی طور پر غیر اسلام کو اپنا دین بنا لیں گے۔ ایک لفظ میں، اِس معاملے کو اسلامائزیشن آف اَن اسلام (Islamization of un-Islam) کہا جاسکتا ہے۔
پیغمبر اسلام ﷺنے اسلام کے ابتدائی تین اَدوار کے بارے میں فرمایا کہ مسلمان ان تین ادوار تک خیر پر قائم رہیں گے۔ حدیث میں آیا ہے کہ: خیر أمتی قرنی، ثمّ الذین یلونہم ثم الذین یلونہم (البخاری، کتاب المناقب، باب فضائل أصحاب النبی) یعنی سب سے بہتر مسلمان میرے دور کے مسلمان ہیں، پھر وہ لوگ جو اس کے بعد آئیں، پھر وہ لوگ جو اس کے بعد آئیں۔ اِن تین ادوار کو ’قُرون مشہود لہا بالخیر‘کہاجاتا ہے۔ وہ تین دور یہ ہیں— دورِ رسالت، دورِ صحابہ، دورِ تابعین۔
تاریخ بتاتی ہے کہ مذکورہ تین دوروں تک مسلم نسلیں کم و بیش، اصل اسلام پر قائم رہیں۔ اس کے بعد اُن کے درمیان بگاڑ شروع ہوا۔ اِس بگاڑ کی فکری بنیاد عباسی خلافت کے زمانے میں پڑی۔ بعد کے زمانے میں جو فکری انحرافات مسلمانوں میں پیدا ہوئے، اُن سب کا آغاز عباسی دو ر میں ہوا۔ یہاں ہم ان انحرافات میں سے کچھ چیزوں کا تذکرہ نمائندہ مثالوں کے طورپر کرتے ہیں۔
دار الاسلام کا نظریہ
فقہاء کی اصطلاح میں دار الاسلام اُس علاقے کو کہا جاتاہے، جہاں مسلمانوں کا سیاسی اقتدار قائم ہو۔ اِس قسم کا واقعہ سب سے پہلے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا۔ ہجرت کے بعد مدینہ میں اہلِ اسلام کی ایک شہری ریاست (city state) قائم ہوگئی۔ اس کے بعد جلد ہی پورے عرب میں مسلمانوں کا سیاسی اقتدار قائم ہوگیا۔ لیکن پیغمبر اسلام نے مدینہ کو یاعرب کودار الاسلام نہیں کہا۔ آپ کے بعد صحابہ اورتابعین نے بھی اِس علاقے کو دار الاسلام کا نام نہیں دیا۔ دارالاسلام کی یہ سیاسی اصطلاح پہلی بار عباسی دور کے علماء اور فقہاء نے اختیار کی۔
شرعی تعریف کے مطابق، دار الاسلام کی یہ اصطلاح بلا شبہہ ایک سیاسی بدعت تھی۔ جو چیز رسول اور اصحابِ رسول کے زمانے میں نہ ہو، اُس کو دین کے نام پر اختیار کرنا بدعت ہے۔ اور دار الاسلام کی اصطلاح وضع کرنے کے بارے میں ایسا ہی ہوا۔
یہ کوئی سادہ بات نہ تھی۔ جن علاقوں کو دارالاسلام کہاگیا، اُن کو اگر مسلمانوں کے زیر قبضہ علاقہ (Muslim occupied land) کہاجاتا تو وہ صرف ایک سیاسی مسئلہ ہوتا، نہ کہ اعتقادی مسئلہ۔ لیکن جب ایسے علاقے کو دارالاسلام کہا گیا تو اس کو اعتقادی تقدس کا درجہ مل گیا، ایک سیاسی معاملے کو اعتقادی درجہ دینے سے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، وہ سب خرابیاں مسلمانوں کے اندر پیدا ہوگئیں۔
مثال کے طورپر جب مسلمانوں کے زیر قبضہ علاقے کو اعتقادی حیثیت دیتے ہوئے اس کو دارالاسلام کہاگیا تو اس کے بعد فطری طور پر یہ فقہی مسئلہ بن گیا کہ جو علاقہ ایک بار دارالاسلام کی حیثیت اختیار کرلے، وہ حُکمی (legal) طورپر ہمیشہ کے لیے دار الاسلام ہے۔ ایسے کسی علاقے پر اگر بعد کو غیر مسلموں کا قبضہ ہوجائے تو مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ وہ قابض گروہ سے لڑ کر دوبارہ اُس کو دارالاسلام بنائیں۔ ایسا کرنا مسلمانوں کے لیے صرف ایک علمی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ وہ اُن کے لیے ایک اعتقادی ذمے داری کی حیثیت رکھتا ہے۔
قدیم زمانے میں سیاسی طاقت (political might) کو سب کچھ سمجھا جاتا تھا۔ ایسے ماحول میں دارالاسلام کا مذکورہ نظریہ بظاہر ایک معقول (rational) نظریہ معلوم ہوتا تھا۔ لیکن موجود زمانہ سیاسی آئڈیالوجی (political ideology) کا زمانہ ہے۔
اِن زمانی تبدیلیوں کے نتیجے میں موجودہ دور میں دار الاسلام کا مذکورہ سیاسی نظریہ ایک غیر معقول (irrational) نظریہ بن چکا ہے۔
اِسی نظریے کے مطابق موجودہ زمانے میں سیاسی افکار کا ارتقا ہوا ہے، اور اِسی نظریے کے مطابق، اقوامِ متحدہ (UNO) کے عالمی منشور (Universal Declaration of Human Rights) پر دنیا بھر کی تمام قوموں نے دستخط کیے ہیں جس کے تحت ایک ملک کی دوسرے ملک پر حکم رانی ناقابلِ تسلیم قرار پاچکی ہے۔
موجودہ زمانے میں مختلف مسلم ملکوں میں جو جہادی گروپ سرگرم ہیں، وہ دارالاسلام کے اِسی قدیم فقہی مسئلے سے اپنا نظریہ اخذ کررہے ہیں۔ اُن کا مانناہے کہ مسلم ایمپائر کے زمانے میں جو علاقے مسلمانوں کے زیر اقتدار تھے، وہ اب بھی حُکماً (legally) دار الاسلام کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کی یہ دینی ذمے داری ہے کہ وہ جہاد کرکے اِن علاقوں پر دوبارہ مسلم اقتدار قائم کریں۔ 9 ستمبر 2001 کو نیویارک کے ورلڈ ٹریڈ سنٹر پر حملہ اور 26 نومبر 2008 کو بمبئی کے تاج محل ہوٹل پر کچھ انتہائی پسند مسلم تنظیموں کا حملہ اِسی فقہی طرزِ فکر کی عملی مثالیں ہیں۔
دار الحرب کا نظریہ
عباسی دور میں جو اسلامی فقہ بنی، اُس میں مسلم علاقوں کے علاوہ، دوسرے علاقوں کو دارلحرب کا درجہ دیاگیا۔ یہ بلاشبہہ ایک خود ساختہ نظریہ تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مسلمان اِن علاقوں کے مقابلے میں اصولی طور پر، برسرِ جنگ (at war) کی حالت میں ہیں۔ اِس معاملے کو جدید اصطلاح کے مطابق، سرد جنگ (cold war) کہا جاسکتاہے۔
یہ بلاشبہہ ایک تخریبی نظریہ ہے۔ اِس نظریے نے مسلمانوں کے اندر وہ ذہن پیدا کیا جس کو ہم اور وہ (we and they) کا نظریہ کہا جاتاسکتا ہے۔ اِس کے بعد مسلمانوں کے لیے پوری دنیا، دوست اور دشمن (friends and enemies) کے دو مختلف گروہوں میں بٹ گئی۔ تمام مسلمان شعوری یا غیرشعوری طورپر اِس تقسیمی ذہن کا شکار ہوگئے۔ ان کو مسلمان ’’اپنے‘‘ نظر آئے، اور دوسری قوموں کے لوگ اُن کو ’’غیر‘‘ دکھائی دینے لگے۔
اِس طرح، دارالحرب اور اِس تصور کے تحت پیدا شدہ نظریات نے تمام مسلمانوں کو فکری طور پر غیر معتدل بنا دیا۔ وہ دوسری قوموں کے لیے اَن فرینڈلی (unfriendly) بن گئے، الا یہ کہ کسی ذاتی انٹرسٹ کے سبب سے بظاہر دوسروں کے ساتھ دوستانہ رویّے کا اظہار کیا جائے۔
دار الکفر کا نظریہ
عباسی دور کے علماء اور فقہاء نے جو نظریات بنائے، اُن میں سے ایک بے بنیاد نظریہ دار الکفر کا نظریہ تھا۔ وہ علاقے جہاں کے لوگ مذہبی اعتبار سے اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہوئے، ایسے علاقوں کو انھو ں نے دار الکفر کا نام دیا۔ یہ ایک سنگین قسم کی بدعت تھی۔ قرآن بار بار ایسے لوگوں کے لیے انسان کا لفظ استعمال کرتا ہے۔گویا کہ قرآنی اعتبار سے، ایسے علاقے دار الانسان تھے، نہ کہ دار الکفر، یہ بلا شبہہ ایک بھیانک قسم کا مبتدعانہ فعل تھا جس کا ارتکاب ہمارے علماء اور فقہاء نے کیا۔
اِس فقہی تسمیہ (nomenclature) کے سنگین نتائج برآمد ہوئے۔ اِس تسمیہ کی بنیاد پر بعد کے زمانے میں جو لٹریچر تیار ہوا اور مسجدوں اور مدرسوں میں جس قسم کی باتیں دہرائی جاتی رہیں، اُس کا فطری نتیجہ یہ ہوا کہ تمام دنیا کے مسلمان دوسری قوموں کو ’’کافر‘‘ سمجھنے لگے۔ کافر کے لفظی معنیٰ صرف منکر کے ہیں۔ لیکن اپنے استعمال کے اعتبار سے وہ ایک سخت قسم کا تحقیری لفظ (derogatory word) بن گیا۔ اِس کے فطری نتیجے کے طورپر یہ ہوا کہ مسلمانوں کے دل میں دوسری قوموں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ ختم ہوگیا۔ وہ شعوری یا غیر شعوری طور اُن کو قابلِ نفرت سمجھنے لگے۔
دار الکفر کا یہ مبتدعانہ نظریہ اتنا پھیلا کہ تقریباً تمام کتابوں میں وہ کسی نہ کسی طرح شامل ہوگیا، وہ مسلمانوں کی سوچ کا ایک لازمی جز بن گیا۔اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے اندر جو تفریقی مزاج (separatist tendency) پیدا ہوا، وہ بلاشبہہ ایک ہلاکت خیز مزاج تھا۔ وہ مسلمانوں کے لیے عالمی برادری کا معتدل حصہ بننے میں مانع ہوگیا۔ اِس بنا پر مسلمانوں کے لیے اِس دنیا میں صرف دو آپشن باقی رہا— یا تو وہ عالمی برادری سے کٹ کر اپنے آپ کو ایک محدود خول میں بند کرلیں، یا مفاد پرستانہ ذہن کے تحت وہ دنیا میں لوگوں کے ساتھ رہیں۔ اِسی دہری روش کا شرعی نام منافقت ہے۔
دار الکفر کا نظریہ سر تاسر ایک خود ساختہ نظریہ ہے۔ قرآن اور حدیث میں اِس نظریے کے حق میں کوئی بنیاد موجود نہیں۔ لیکن وہ مسلمانوں کے اندر اتنا زیادہ پھیلا کہ اب شاید کوئی ایک شخص بھی اِس نفسیات سے خالی نہیں۔ اِس کا سبب غالباً یہ ہے کہ مسلمانوں کو اِس نظریے کے ذریعے ایک فرضی یقین (false conviction) حاصل ہوتا ہے۔ تمام دوسرے لوگوں کو کافر قرار دے کر وہ بالواسطہ انداز میں اپنے لیے یہ یقین حاصل کرتے ہیں کہ دوسرے تمام لوگ بھٹکے ہوئے ہیں اور صرف ہم ہیں جو صحیح راستے پر قائم ہیں، دوسرے تمام لوگوں کے لیے جہنم ہے، اور ہمارے لیے ابدی جنت، وغیرہ۔
اِسی نظریے کا ایک بھیانک نقصان یہ ہے کہ بعد کے دور میں تقریباً تمام مسلمانوں کی سوچ مسلم رُخی سوچ (Muslim-oriented thinking) بن گئی۔ یہ کہنا بلا مبالغہ درست ہوگا کہ بعد کے زمانے میں مسلمانوں کے اندر انسان رُخی سوچ(man-oriented thinking) کا ارتقانہ ہوسکا، اور اِس فکری المیہ کی ذمے داری تمام تر دار الکفر کے اِسی فقہی نظریے پر ہے۔
موجودہ زمانہ ایک اعتبار سے تحریکوں کا زمانہ تھا۔ خاص طورپر پرنٹنگ پریس کا دو آنے کے بعد مسلمانوں کے اندر ہر جگہ ہزاروں کی تعداد میں تحریکیں اٹھیں، مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ اِن میں سے کوئی بھی قابلِ ذکرتحریک انسان رخی تحریک نہ تھی۔ تمام کی تمام معلوم تحریکیں، مسلم رُخی تحریکیں تھیں۔ اِس صورتِ حال کا مزید نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان فکر ِ انسانی کے عالمی دھارے (mainstream) میں شامل نہ ہوسکے، وہ عالمی فکر کے اندر ایک محدود جزیرہ بن کر رہ گئے۔
بعد کے زمانے کے مسلم مفکرین نے جن غیر اسلامی نظریات کو اسلامائز کیا اور اُن کو مسلمانوں کے اندر پھیلایا، اُن میں سے ایک مہلک نظریہ وہ تھا جس کو خلافتِ ارضی کا نظریہ کہا جاتا ہے۔ مسلم مفکرین نے خود ساختہ طورپر اپنے لیے یہ ٹائٹل لے لیا کہ وہ خلیفۃ اللّٰہ فی الارض ہیں۔ اِس طرح، مسلمان گویا کہ زمین پر خدا کے نائب ہیں۔ اُن کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ خدا کی طرف سے ملے ہوئے قانون کو خدا کی نیابت میں زمین پر نافذ کریں۔
خلافت کا یہ نظریہ کسی نہ کسی طورپر بعد کے زمانے کے مسلمانوں کی فکر پر چھاگیا۔ اِسی کی روشنی میں دوسری چیزوں کی توجیہہ وتشریح کی جانے لگی۔ مثلاً حدیث میں آیا ہے کہ بعد کے زمانے میں اسلام کا کلمہ ساری دنیا کے ہر گھر میں داخل ہوجائے گا۔ اِس حدیث کی تشریح مذکورہ نظریۂ خلافت کے تحت کی گئی اور اُس کا یہ مطلب بتایا گیا کہ آخری زمانے میں اسلام کی حکومت ساری دنیا میں قائم ہوجائے گی۔ یہ تشریح بلا شبہہ ایک غیر علمی تشریح ہے، وہ سر تاسر بے بنیاد ہے۔
مذکورہ حدیثِ رسول میں کلمۂ اسلام (word of Islam) کا لفظ ہے، نہ کہ حکومتِ اسلام (rule of Islam) کا لفظ۔ اِس سے واضح طورپر یہ ثابت ہوتا ہے کہ اِس حدیث میں جس واقعے کا ذکر ہے، اُس سے مراد اسلام کے کلمہ (word)، یا اُس کے پیغام کا ساری دنیا کے تمام گھروں میں پہنچ جانا ہے، نہ کہ مسلم اقتدار کا ساری دنیا میں قائم ہوجانا۔ حدیث کی مذکورہ تشریح، حدیث کا سیاسی کَرن (politicization) ہے، وہ حدیث کے اصل مفہوم کی وضاحت نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ حدیث میں جس واقعے کا ذکر ہے، وہ کمیونکشن کے ذریعے ہونے والا واقعہ ہے، نہ کہ فوج کشی کے ذریعے ہونے والا واقعہ ہے۔
اِس سیاسی طرزِ فکر کے بہت سے نقصانات ہیں۔ اُن میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر روحانی اور تعمیری طرز فکر کا تقریباً کُلّی خاتمہ ہوگیا۔ داخلی اعتبار سے اُن کے اندر وہ طرزِ فکر موجود نہیں جس کو روحانی طرزِ فکر (spiritual thinking) کہاجاتا ہے۔ اور خارجی اعتبار سے وہ اُس طریقِ کار سے بے خبر ہیں جس کو موجودہ زمانے میں تعمیری طریقِ کار(constructive method) کا نام دیا جاتا ہے۔
مکمل اسلام کا نظریہ
موجودہ زمانے میں مسلمانوں کے اندر ایک لفظ بہت عام ہوگیا ہے، وہ یہ کہ اسلام ایک مکمل نظام ہے۔ عرب مسلمان اور غیر عرب مسلمان دونوں فخر کے ساتھ یہ لفظ بولتے ہیں۔ بظاہر یہ اسلام کی ایک خوب صورت تعریف معلوم ہوتی ہے، لیکن وہ اسلام کی ایک مبتدعانہ تشریح ہے، اور ہر مبتدعانہ تشریح کا نتیجہ بلاشبہہ ہلاکت ہوتا ہے۔ اِس تشریح کے بے اصل ہونے کا واضح ثبوت یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں کہیں بھی اسلام کے لیے یہ تعبیر اختیار نہیں کی گئی کہ اسلام ایک مکمل نظام ہے۔
مکمل اسلام کے اِس نظریے نے موجودہ زمانے کے مسلمانوں کے لیے صرف دو بُرے چوائس (evil choice)کا امکان باقی رکھا ہے— ایک برا چوائس یہ کہ وہ ’’مکمل اسلام‘‘ پر قائم ہونے کے لیے ساری دنیا سے مستقل طورپر لڑتے رہیں۔ کیوں کہ جب تک وہ ساری دنیا کو سیاسی اعتبار سے مغلوب نہ کرلیں، وہ اپنے مفروضہ مکمل اسلام پر قائم نہیں ہوسکتے۔ اُن کے لیے دوسر ابُرا چوائس یہ ہے کہ وہ فکری اعتبار سے تو اسلام کو مکمل نظام سمجھیں، لیکن مفاد پرستانہ ذہن کے تحت، وہ دوسرے نظاموں سے سمجھوتہ (compromise) کرلیں۔ کیوں کہ دوسرے نظاموں سے سمجھوتہ کیے بغیر اُن کے لیے اِس دنیا میں مادّی فوائد کا حصول ممکن نہیں۔